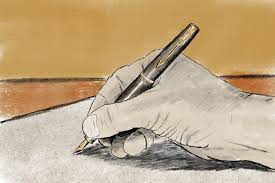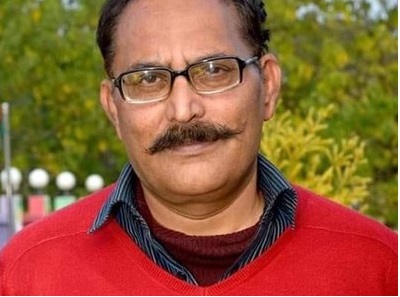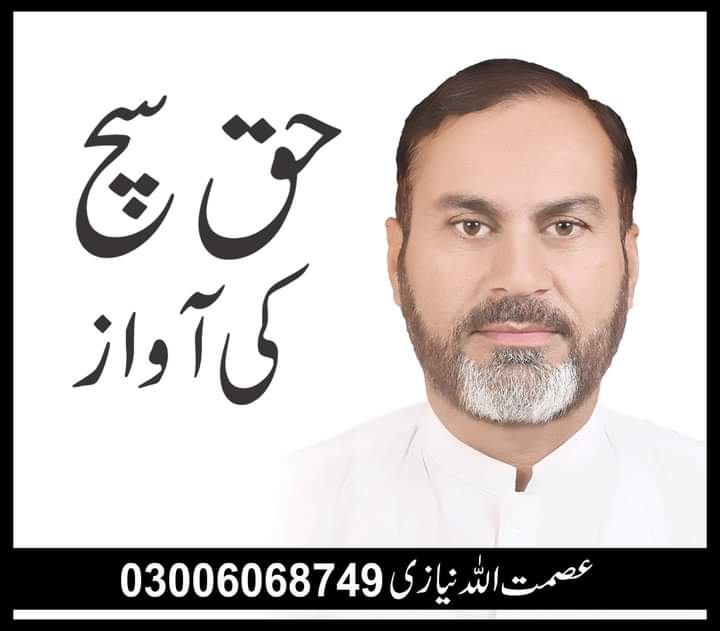خدا پر ایمان اور جدید سائنس۔حمزہ ابراہیم
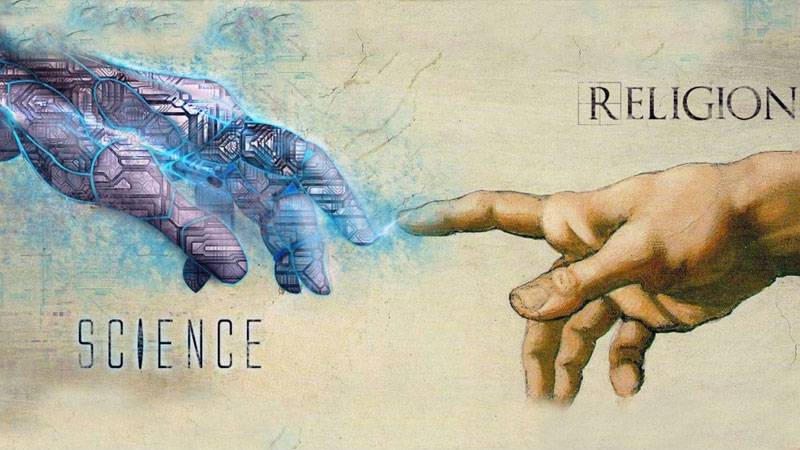 غزہ کا موجودہ بحران بھی مذاہب کی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے۔ شام کو تباہ کرنے میں مذہبی شدت پسندوں کی حماقت سے اسرائیل نے فائدہ اٹھایا۔ غلط تفسیر کر کے سیاسی فائدے اٹھانا ہر مذہب میں ہو رہا ہے۔ بدھ مت جیسے پرامن مذہب کے پیروکار بھی برما میں فاشزم کا شکار ہو گئے ہیں۔وہ روہنگیا مسلمانوں کے شہری حقوق ختم کر کے ان کا قتل عام کرتے رہے ہیں۔جدید سائنس کے مطابق دنیا مسلسل ہونے والے اتفاقات پر قائم ہے۔ بنیادی ذرات توانائی کی مختلف شکلیں ہیں جن کے خواص الگ الگ ہیں اور وہ اتفاقی طور پر پیدا اور فنا ہوتے ہیں۔ ان اتفاقات میں ہر چیز کے خواص کی مناسبت سے نظم ہوتا ہے۔ ایک قسم کے سب اتفاقات (events) ایک جیسے نظم (distribution) سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے جب بڑے اجسام تشکیل پاتے ہیں تو ان بڑے اجسام میں ایک علت و معلول والا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں چھوٹے ذرات میں علت و معلول کے اصول کی پابندی ضروری نہیں ہوتی، وہیں روزمرہ کی زندگی میں علت و معلول کا قانون ایک واقعیت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہر معلول کی کوئی علت ہوتی ہے جو زمانی طور پر اس سے پہلے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ وہ اور معلول اپنی اصل میں جڑے ہوتے ہیں، ایک طرح کا ذاتی تعلق رکھتے ہیں۔
غزہ کا موجودہ بحران بھی مذاہب کی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے۔ شام کو تباہ کرنے میں مذہبی شدت پسندوں کی حماقت سے اسرائیل نے فائدہ اٹھایا۔ غلط تفسیر کر کے سیاسی فائدے اٹھانا ہر مذہب میں ہو رہا ہے۔ بدھ مت جیسے پرامن مذہب کے پیروکار بھی برما میں فاشزم کا شکار ہو گئے ہیں۔وہ روہنگیا مسلمانوں کے شہری حقوق ختم کر کے ان کا قتل عام کرتے رہے ہیں۔جدید سائنس کے مطابق دنیا مسلسل ہونے والے اتفاقات پر قائم ہے۔ بنیادی ذرات توانائی کی مختلف شکلیں ہیں جن کے خواص الگ الگ ہیں اور وہ اتفاقی طور پر پیدا اور فنا ہوتے ہیں۔ ان اتفاقات میں ہر چیز کے خواص کی مناسبت سے نظم ہوتا ہے۔ ایک قسم کے سب اتفاقات (events) ایک جیسے نظم (distribution) سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان سے جب بڑے اجسام تشکیل پاتے ہیں تو ان بڑے اجسام میں ایک علت و معلول والا سلسلہ دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ جہاں چھوٹے ذرات میں علت و معلول کے اصول کی پابندی ضروری نہیں ہوتی، وہیں روزمرہ کی زندگی میں علت و معلول کا قانون ایک واقعیت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ہر معلول کی کوئی علت ہوتی ہے جو زمانی طور پر اس سے پہلے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ وہ اور معلول اپنی اصل میں جڑے ہوتے ہیں، ایک طرح کا ذاتی تعلق رکھتے ہیں۔
روزمرہ کی منطق کا مطلق انکار کرنا سائنسی رویہ نہیں ہے اور اس کے بڑے اجسام تک محدود ہونے کا انکار کرنا بھی کم علمی ہے۔ منطق کے اصولوں کی بنیاد میں چھوٹے اجسام کو بیان کرنے والے سائنسی اصول موجود ہیں۔ زندہ اشیاء کا ارتقاء بھی اتفاقات کے اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ یونانی منطق کی پابندی میں غلو کا شکار ہیں وہ نظریۂ ارتقاء، بگ بینگ،یا دیگر گہرے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کئے بنا ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ان کے اتفاقی ہونے (randomness) کو ٹھیک سے سمجھنا ضروری ہے۔
تسلسل کے محال ہونے کو بھی ریاضی میں پیشرفت باطل ثابت کر چکی ہے۔ بعض لامتناہی سلسلوں کا قابل جمع ہونا سائنس میں کئی ایک مظاہر کی درست تشریح کیلئے استعمال ہو رہا ہے۔ سائنس میں زمان و مکان کا حادث اور کائنات کا حادث ہونا بھی ثابت ہو چکا ہے۔ نیز ان کی نسبیت بھی ثابت شدہ ہے۔ نسبیت صرف زمانی نہیں بلکہ مکانی اور جسمانی بھی ہے۔
کائنات ابتداء میں چھوٹے ذرات کے اکٹھ کی صورت میں تھی جو ایک بادل کی طرح تھے۔ بعد میں بڑے اجسام بنتے گئے۔ تاہم اب بھی دنیا کے تمام مظاہر کے پیچھے اتفاقات اور ان کے گوناگوں طریقے ہیں۔
ایسے میں اگر یہ کہا جائے کہ ہر اتفاق کے رونما ہونے میں ایسے خدا کا فیصلہ کارفرما ہے، جو ان سے ذاتاً جدا ہے اور ان سے علت و معلول جیسا زمانی رابطہ نہیں رکھتا، تو اس کو یونانی تصور خدا سے جدا سمجھنا چاہئے جس میں پرانی سوچ کے مطابق علت و معلول کا اصول خدا اور کائنات پر لاگو کیا جاتا تھا۔
قرآنی تصورِ خدا
یونانی تصور خدا کے برعکس قرآن میں خدا کے بارے میں یہ معلومات دی گئی ہیں:
1۔ جب حضرت موسیٰ ؑ سے خدا کے بارے سوال ہوا تو انہوں نے کہا:
قَالَ رَبُّنَا الَّذِی اَعطٰی کُلَّ شَیءٍ خَلقَہٗ ثُمَّ ہَدٰی. (سورہ طہ، آیت 50)
ترجمہ: ”انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت کی۔“
علت و معلول کے یونانی تصور کے برعکس یہاں خدا ہر مظہر کی علت نہیں بلکہ ہر ایک کا براہِ راست خالق ہے۔ خلق ہونے کے عمل میں کوئی واسطہ نہیں، اور خدا ہی کی ہدایت کے مطابق ہر مظہر الگ طریقے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ مخلوق کو پیدا کرنے میں خدا واسطوں کا محتاج ہو۔ خدا کو قادرِ مطلق ماننے کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ یونانی تصور خدا کے مطابق خدا چیزوں کو بنانے میں علتوں کے سلسلے کا محتاج ہے، جس میں پہلی علت وہ اور دوسری علت کوئی اور ہے، علیٰ ہذا القیاس۔
2۔ قرآن میں خدا کی ایک صفت باری آئی ہے جو افلاطون کے مثالی موجودات کے غیر سائنسی تصور کے برعکس بغیر مثال کے خلق کرنے کے معنوں میں ہے۔
3۔ سورہ اخلاص میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خدا میں سے کچھ نہیں نکلا، نہ خدا کسی سے نکلا ہے: لم یلد و لم یولد۔ اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ خدا اور مخلوقات اپنی اصل میں الگ ہیں۔ یہی بات اس آیت: لیس کمثلہ شیء،اس اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، سے بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ اہلبیتؑ کے اقوال میں آیا ہے کہ خدا کی ذات خلق سے خالی ہے اور خلق خدا سے خالی ہے۔ وہ مخلوقات کی مجانست و مشابہت سے پاک ہے۔
ہمارا دماغ اشیا کا علم اعداد اور الفاظ کی مدد سے حاصل کرتا ہے۔ الفاظ و اعداد سے ذہن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر خدا کو اشیا سے بالکل جدا سمجھا جائے تو اس کی ذات کا علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی حقیقت اعداد کی شکل میں بیان نہیں ہو سکتی۔
عقل خدا کے بارے جو بھی تصور بنا لے وہ درست نہیں ہو گا کیونکہ ہماری عقل ہمارے دماغ کے مخلوقات سے تعامل کے نتیجے میں بنتی ہے۔ صرف سائنسی طریقۂ کار ہی نہیں، کسی بھی ذریعے سے انسانی عقل خدا کی ذات کا علم حاصل نہیں کر سکتی۔ عقل صرف مخلوقات کا علم حاصل کر سکتی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں موضوع سائنس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانی عقل کی حدود سے باہر ہے، اس کا علم ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایمان لایا جا سکتا ہے اور قرآن میں خدا پر ایمان لانے ہی کی دعوت دی گئی ہے، فلسفیانہ دلیلیں قائم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔
جدید سائنس توانائی کا زمان و مکان کے ساتھ تعلق بھی ثابت کر چکی ہے۔ لیس کمثلہ شیء کا نتیجہ خدا کا زمان و مکان سے پاک ہونا بھی ہے۔
4۔ خواجہ نصیر الدین طوسی وغیرہ نے خدا کو واجب الوجود اور مخلوقات کو ممکن الوجود کہا ہے۔ اتفاقات ممکن الوجود ہی ہیں اور جب ان کے رونما ہونے اور نہ ہونے میں امکان (probability) کا عمل دخل ہے تو عقل ایسے خدا پر ایمان کو لازمی سمجھتی ہے جس کا ہونا حتمی اور یقینی ہو۔ اس ایمان کے بغیر انسان کی عقل توازن کھو سکتی ہے۔
5۔ خدا کے بارے میں ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ خدا پر ایمان کے بغیر انسان کو درندگی سے بچنے میں مشکل ہوتی ہے۔ زندہ اشیاء کے ارتقاء میں ہم نوع کے ساتھ تعاون بقا کی بنیادی شرط تھی۔ انسانوں کو جب قوت گویائی عطا ہوئی تو انسانوں کا آپس میں تعاون باقیوں کی نسبت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یہ سیاست کی ابتداء تھی جس نے انسان کو زمین کی باقی مخلوقات پر فضیلت دے دی۔ یہاں مشترکہ تصور خدا پر ایمان نے انسانوں کو مل کر مشکلات کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیا۔
بعض ملحدین سائنس کے نام پر یونانی تصور خدا کو رد کر رہے ہیں لیکن اس بنیاد پر مذاہب کے پیروکاروں میں موجود اس تصور خدا سے بھی انکار کر دینا غیر سائنسی رویہ ہے۔ خود ان حضرات کے ہاں بھی مذہب سے لگاؤ پایا جاتا ہے۔ رچرڈ ڈاکنز نے خود کو ثقافتی طور پر مسیحی کہا تو پروفیسر سٹیون وائنبرگ خود کو یہودی کہتے تھے۔ جس خدا کو یہ نہیں مانتے وہ تو ارسطو اور فلوطین کا خدا ہے۔ اگر یہ اپنے سماج کے مطابق ایک مذہب سے جڑے ہیں تو باقی لوگ بھی اپنے مذہب سے جڑے رہ سکتے ہیں۔
انسان کا دماغ بہت پیچیدہ ہے اور اس میں ہم نوع کے ساتھ تعاون کی کوئی بنیاد نہ ہو تو اس کا شر بہت بڑھ سکتا ہے۔ جنگ عظیم اول اور دوم میں یہی شر کھل کر سامنے آیا تھا۔ اب جبکہ دنیا میں دوبارہ جنگ عظیم دوم سے پہلے والا ماحول پیدا ہو رہا ہے تو ایسے میں باہمی تعاون اور اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے۔ انسان معاشرہ بنانے میں اخلاقیات، ضابطوں اور رسوم و رواج کا محتاج ہے۔
انسان خدا کی ذات کا علم اگر حاصل نہیں کر سکتا تو اس پر ایمان رکھ کر اخلاقیات کو ایک محکم بنیاد فراہم کر سکتا ہے اور یوں ایک مہذب زندگی گزار سکتا ہے۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت پر غور کرنے کو اس معرفتِ نفس کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے جو خدا پر ایمان میں مددگار ہوتی ہے۔ انسانی جسم کی معرفت سے زیادہ دوسرے افراد اور انسانوں کے مختلف گروہوں سے اپنے رابطے کی معرفت ایمان میں اضافے میں زیادہ مددگار ہو سکتی ہے۔
مذہب کا منفی استعمال
البتہ بعض شاطر لوگ مذہب کا منفی استعمال بھی کرتے ہیں۔(سورہ توبہ، آیت 34) اس لئے اپنی زندگی کے فیصلوں کیلئے اپنی عقل پر بھروسہ کرنا اور اپنی عقل کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی بار بار عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پیشہ ور مذہبی رہنما مقدس کتابوں کی ایسی تفسیر کرتے ہیں جو مذہب اور ایمان کے مقصد کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ مذاہب کے درمیان اختلافات کو جتھہ بندی کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ یوں انسان ایک گروہ سے تو منسلک ہوتے ہیں اور وہاں باہمی اتحاد پر زور دیتے ہیں، لیکن دوسرے گروہوں کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں۔ ان کی عقلیں ماؤف ہو جاتی ہیں۔ یہ کام باقی مذاہب کی طرح اسلام کے معاملے میں بھی ہو رہا ہے۔ مذہب کو پیشے کے طور پر اختیار کرنے والوں کو سیاسی رہنما نہیں سمجھنا چاہئے۔
غزہ کا موجودہ بحران بھی مذاہب کی غلط تفسیر کا نتیجہ ہے۔ شام کو تباہ کرنے میں مذہبی شدت پسندوں کی حماقت سے اسرائیل نے فائدہ اٹھایا۔ غلط تفسیر کر کے سیاسی فائدے اٹھانا ہر مذہب میں ہو رہا ہے۔ بدھ مت جیسے پرامن مذہب کے پیروکار بھی برما میں فاشزم کا شکار ہو گئے ہیں۔وہ روہنگیا مسلمانوں کے شہری حقوق ختم کر کے ان کا قتل عام کرتے رہے ہیں۔
یہاں اس نکتے کی طرف اشارہ بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں انتہاپسندوں کا تناسب بہت کم ہے۔ اکثر لوگ معقول زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ مسلمان صدیوں تک غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہے ہیں۔ موجودہ شدت پسندی اسلام کا لازمہ نہیں ہے۔ ہر دہشتگرد مسلمان نہیں ہوتا۔
انتہاپسندی نقصان دہ ہے
ظلم اور جہل آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جاہل ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ غلط تفسیر کا معاملہ صرف مذہب کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ مارکسزم اور قوم سے محبت کی غلط تفسیروں نے بھی دنیا میں بہت تباہی مچائی ہے۔ کمیونسٹ گروہ بنانے کا مقصد بھی غریبوں کے حالات سدھار کر ان کو جدید علوم سے بہرہ مند ہونے کے قابل بنانا ہو تو یہ ایک مثبت کام ہو سکتا ہے۔ لیکن بہت سے کمیونسٹوں نے اپنا مقصد معاشی تفریق کا خاتمہ اور امیروں کی بربادی بنا لیا۔ یوں وہ وقت جو غریبوں کی بہتری کیلئے استعمال ہو سکتا تھا وہ سرمایہ داروں کے خلاف نفرت انگیزی اور ان کے جان و مال پر حملوں میں ضائع ہو گیا۔ مارکس کی ہر بات درست نہیں تھی۔
قوم پسندی اور وطن دوستی کی درست تفسیر بھی قوم کو علوم سے آشنا کرنا اور وطن کو آباد کرنا، وغیرہ ہونی چاہئے۔ اگر دوسری قوموں یا ملکوں کو تباہ کرنا مقصد بنا لیا جائے تو یہ غلط بات ہو گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں قوم پرستوں کی انتہاپسندی کو اسرائیل نے استعمال کر کے ان کے ملک کو نقصان پہنچایا۔ خود ہمارے ہاں بعض قوم پرست ہندوستان کے ہاتھوں کھلونا بنے۔ بنگلہ دیش میں بنگالی قوم پرستی نے بہاری مہاجر مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔
جہلِ مرکب سے بچنے کی ضرورت
اہلِ تصوف و عرفان کے جہلِ مرکب سے بچنا بھی ضروری ہے۔ وہ مبہم باتیں کر کے زبان کا معنوی نقصان کرتے ہیں۔ وہ الفاظ میں الجھاتے ہیں۔ وہ علم، وجود، عشق، غرض ہر لفظ کا ایسا ٹیڑھا مطلب نکالتے ہیں جس کی غیر جانبدار لوگ تصدیق نہیں کر سکتے۔ اکثر اوقات تو وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یوں زبان کا جو مقصد ہے، یعنی باہمی افہام و تفہیم، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ زبان کی تباہی سے حماقت اور حماقت سے تشدد جنم لیتا ہے۔ جدید دور میں سوشل میڈیا کی بدولت وہ یہ غلط فہمیاں دوسروں تک بھی زور و شور سے منتقل کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر لفظ کا معنی بگاڑ دیں۔ یوں عقلوں کو ماؤف کر کے اپنا دھندہ چلائیں۔
جن لوگوں کی عقلوں کو اہلِ تصوف و عرفان خراب کرتے ہیں وہ ان کی خانقاہوں تک محدود نہیں رہتے اور کسی بھی شدت پسند تنظیم کیلئے مفت کے کارکن بن جاتے ہیں۔ احمق انسان شدت پسند ہوتا ہے۔ کسی بیوقوف انسان کو کوئی بھی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف الحاد سے بچاتا ہے، لیکن اگر نوجوانوں کو الحاد سے بچا کر خارجی بنانا ہے تو اس سے کیا ملے گا؟
آج انتہاپسندوں کی وجہ سے ہی نیتن یاہو اس مقام پر آیا ہے جہاں اس کے بقول یہودیہ (Judea) کے شیر کی دھاڑ پورے مشرق وسطیٰ میں سنی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے شام میں عرب قوم پرستوں کے خلاف جس اخوان المسلمون کو استعمال کیا، ایران میں اسی اخوان المسلمون کے خلاف ایرانی قوم پرستوں کو استعمال کر لیا۔ مغرب میں وہ ایونجیلیکل مسیحیت کو مفت کی لابی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
الحاد کا جواب تصوف کی حماقت نہیں بلکہ قرآن کا تصورِ خدا ہے۔
زبان کی تباہی کے دیگر اسباب
زبان کی بربادی اہل سیاست کے ہاتھوں بھی ہوتی ہے۔ وہ بلند بانگ وعدے کرتے ہیں اور خطابت پر زور دیتے ہیں۔ یونانیوں کے ہاں بھی سوفسطائی خطابت سے کام چلاتے تھے اور الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے ان کے معنوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ آج کل غیر تربیت یافتہ صحافی بھی زبان کے ذریعے آگ بھڑکا رہے ہیں۔ ہر وقت بریکنگ نیوز چلائی جا رہی ہوتی ہے۔ ویوز لینے کیلئے بے تکی اور مصالحہ دار باتیں کی جاتی ہیں۔ غزہ کے موجودہ بحران میں بھی زبان کے منفی استعمال اور جان بوجھ کر ابہام پھیلانے کا عمل دخل ہے۔
مادری زبانوں کا المیہ
ہمارے ہاں ایک المیہ یہ رہا ہے کہ مقامی زبانوں میں ماضی میں صرف شاعری ہوتی رہی ہے۔ وہ شاعری بھی تصوف سے لت پت ہے۔ لوگ کئی طرح کے جاہلانہ خیالات میں قید ہیں۔ اس مسئلے کا مناسب حل یہی ہے کہ بچوں کو انگریزی میں ہی تعلیم دی جائے تاکہ جدید علوم تک انکی رسائی ہو سکے۔ زبان محض ایک آلہ ہے، اگر علم انگریزی میں ہے تو وہی سیکھنی چاہئے۔ زنگ زدہ آلے کے استعمال پر اڑے رہنا درست نہیں ہے۔ مادری زبان سے تھوڑی بہت آشنائی کافی ہے۔
طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ اٹھائیں
اسلام ہمیں اپنی طاقت کی حد تک ظلم اور جہالت کی مخالفت کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ جدید دور میں جتھہ بند تشدد کے اسباب میں جہالت بھی ایک بڑا سبب ہے۔ خدا پر ایمان ہمیں ان اندھیروں کے مقابلے میں چھوٹے سے چراغ جلانے کا حوصلہ دے سکتا ہے۔ تاہم اپنی طاقت سے زیادہ بڑا چراغ جلانا درست روش نہیں۔(سورہ بقرہ، آیت 286) اس سے آپ زندگی کا توازن کھو سکتے ہیں اور جلد بازی میں کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔
واپس کریں